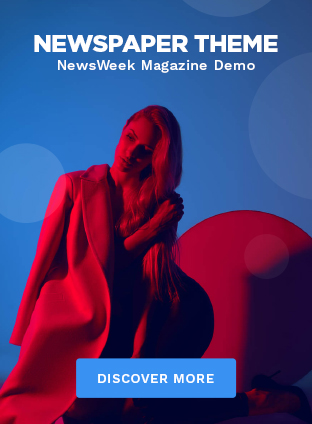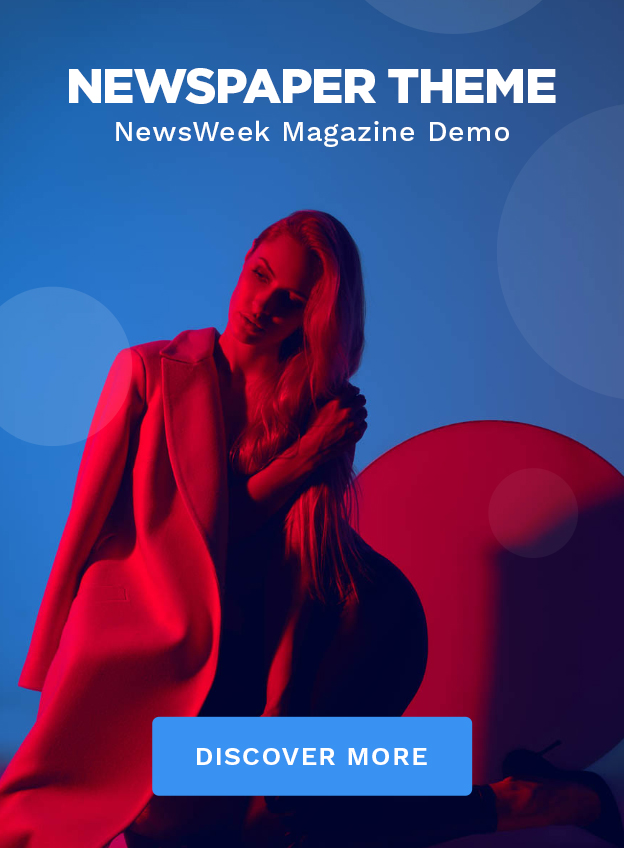تحریر: علی رحمت

گلگت بلتستان کی فضا ایک خوبصورت مگر متضاد منظر پیش کرتی ہے۔ پہاڑوں کی خاموشی میں ایک ایسا شور چھپا ہے جو بظاہر سنائی نہیں دیتا مگر دلوں کے اندر مسلسل گونجتا رہتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہاں محبت، امن اور بھائی چارے کی فضا ہے، کہ شیعہ اور سنی ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نفرت نہیں۔ لیکن اگر ذرا قریب جاکر دیکھو تو احساس ہوتا ہے کہ اس خاموشی کے نیچے کتنی گہری خلیج چھپی ہے۔
محلے الگ الگ ہیں، مساجد کی اذانیں الگ لہجوں میں اٹھتی ہیں، دفاتر، نوکریاں اور ادارے تک مسلکی تقسیم کے تابع ہیں۔ شادی بیاہ کے رشتوں پر مذہب کی مہر لگی ہے، اور ذاتی جھگڑے لمحوں میں مذہبی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ سب اس معاشرتی تضاد کا عکاس ہے جو ہم زبان سے تسلیم نہیں کرتے مگر عمل سے روز دہراتے ہیں۔
یہ کہنا کہ مولوی نے دین کو بانٹا، ایک سادہ مگر جذباتی الزام ہے۔ سچ یہ ہے کہ مولوی وہی بیچتا ہے جو ہم خریدنے کے عادی ہیں۔ اس کا منبر ہماری سماجی نفسیات کا آئینہ ہے۔ وہ ہمارے اندر کے اختلافات کو صرف زبان دیتا ہے، انہیں پیدا نہیں کرتا۔ وہی بات بولتا ہے جو ہمارے دلوں میں پہلے سے پکی ہوتی ہے۔ اگر لوگ تعصب چاہتے ہیں تو وہ تعصب بیچے گا، اگر لوگ اتحاد مانگیں تو وہ اتحاد کی بات کرے گا۔
چمکتے ہوئے مدرسوں اور دکان دار مولویوں کے گھروں میں دولت کے انبار ملتے ہیں، مگر جو مولوی خلوصِ نیت سے دین سمجھاتا ہے، وہ اکثر غربت اور گمنامی میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ مسئلہ مولوی نہیں، ہم ہیں جو سچ سے زیادہ سننے کے لیے وہ بات چاہتے ہیں جو ہمارے تعصبات کو جواز دے سکے۔
اختلاف بذاتِ خود برائی نہیں۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ فکری تنوع اسی طرح ضروری ہے جیسے درخت کے لیے مختلف سمتوں سے آنے والی ہوا۔ مگر جب اختلاف کو دشمنی کا دوسرا نام بنا دیا جائے، تو معاشرہ اپنی روح کھو دیتا ہے۔ گلگت بلتستان میں یہی ہوا ہے۔ یہاں اختلاف مکالمے کی بجائے نفرت کی بنیاد بن گیا ہے۔ ایک کا ہیرو دوسرے کا مجرم ہے، ایک کی دعا دوسرے کے لیے لعنت۔ کسی کی موت پر دوسرا جشن مناتا ہے،
کسی کے زخم پر کوئی مرہم نہیں رکھتا۔ ہم نے دین کو نہیں بانٹا، ہم نے انسان کو بانٹا ہے۔ مسجدیں بڑھ گئیں مگر دل چھوٹے پڑ گئے۔ تعلیمی ادارے، سرکاری محکمے اور سماجی ڈھانچے اسی تقسیم کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر ادارے خود فرقہ وارانہ بنیاد پر کام کریں تو ان سے انصاف کی توقع کیسے رکھی جائے؟ یہ وہ بنیادی بیماری ہے جسے ہم مذہبی نہیں بلکہ اخلاقی سمجھ کر علاج کریں تو شاید شفا ممکن ہو۔ اصل مسئلہ عقیدے کا نہیں، رویّے کا ہے۔
ہم نے اپنے ایمان کو اپنے اخلاق سے الگ کر دیا ہے، اس لیے عبادتوں کی کثرت کے باوجود دلوں میں وحشت باقی ہے۔ پھر سوشل میڈیا کا وہ نرالا تماشا ہے، جہاں سب خوش ہیں، سب متحد ہیں، سب امن کے داعی ہیں۔ وہاں کی دنیا ایک مصنوعی خواب کی طرح ہے جس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، مگر زمین پر قدم رکھتے ہی وہی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں جنہیں ہم آن لائن گرادیتے ہیں۔
یہ خود فریبی دراصل سب سے بڑا زہر ہے، کیونکہ جب انسان بیماری کا انکار کر دیتا ہے تو علاج کا امکان بھی مر جاتا ہے۔ اس ساری صورتِ حال کا حل کسی بڑی تقریر یا نعرے میں نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی کوششوں میں پوشیدہ ہے۔ ایک مشترکہ چائے، ایک مشترکہ محفل، ایک مدرسہ جہاں دونوں مکاتبِ فکر کے بچے ساتھ پڑھیں، ایک پارک جہاں سب کے بچے کھیل سکیں یہی وہ چھوٹے پل ہیں جو بڑے فاصلے کم کر سکتے ہیں۔
جب ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیں گے، تب ہی وہ خاموش نفرتیں تحلیل ہونا شروع ہوں گی جو نسلوں سے ہمارے خون میں گھل چکی ہیں۔ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے رویّوں کو دین کا لباس پہنا دیا ہے۔ ہم نے تعصب کو عقیدت کا نام دے دیا ہے، اور بدگمانی کو ایمان کی علامت سمجھ لیا ہے۔ مولوی کے پاس اختیار کم ہے،
مگر اس سے بھی زیادہ اختیار اس عوام کے پاس ہے جو سننے، سمجھنے، اور بدلنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ جب ہم نفرت خریدنا چھوڑ دیں گے، تو وہ بیچنا بھی بند کر دے گا۔
گلگت بلتستان کے پہاڑ شاید ایک دن پھر وہ منظر دیکھیں جب اذان کی آواز فرقوں میں نہیں، انسانوں میں گونجے گی۔ جب محلے کے بچے ایک ہی کھیل میں ہنسیں گے، جب شادیوں کے دروازے ایمان کے نام پر نہیں، محبت کے نام پر کھلیں گے۔ یہ خواب ابھی دور ہے، مگر ناممکن نہیں۔ اگر ہم اپنی ذات کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ روشن کر لیں تو اندھیرا خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا۔ کیونکہ اصل انقلاب نعرے سے نہیں، دل کی نرمی سے شروع ہوتا ہے اور وہی نرمی اس سرزمین کو دوبارہ انسانوں کا وطن بنا سکتی ہے۔